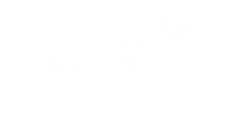سوشل میڈیا پر کالم پوسٹ ہوجائے تو اس کے نیچے کمنٹ لکھنے والوں میں ہمیشہ تین یا چار افراد زیر بحث آئے موضوع کو قطعاً نظرانداز کرتے ہوئے یاد فقط یہ دلاتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ نام کی بھی ایک شے ہوتی ہے۔ مجھ جیسے قلم گھسیٹ کو اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اخبار کے لیے لکھنے اور ٹی وی پر بولنے سے گریز اختیار کرلینا چاہیے۔
ابتداً ایسے تبصروں کو سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد بھلادیا کرتاتھا۔ بتدریج مگر دل میں یہ خواہش ابھرنا شروع ہوگئی کہ ریٹائرمنٹ کا مشورہ دینے والوں کا کھوج لگایا جائے۔ اس کے لیے ان افراد کے فیس بک وغیرہ پر بنائے اکائونٹس میں فراہم کردہ ’شناخت اور تعارف‘ سے رجوع کیا۔ محض چند گھنٹوں کی تحقیق نے مگر سمجھادیا کہ ریٹائرمنٹ کا مشورہ دینے والے سب افراد ہمارے مقبول ترین سیاستدان کے گفتار کے غازی مارکہ فدائی ہیں۔ ان سب کو فرداً فرداً یہ اطلاع نہیں دے سکتا کہ وہ جس کے فدائی ہیں عمر میں مجھ سے مناسب حد تک بڑے ہیں۔ کرشمہ ساز کھلاڑی کی حیثیت سے شروع ہوکر سیاست میں آئے توبالآخر اگست 2018ء میں وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوگئے۔ گزشتہ ایک برس سے جیل میں ہیں لیکن پاکستان کو ایک بار پھر ’نیا‘ بنانے کے لیے بے چین بھی۔ تمام تر مشکلات کے باوجود اگر وہ سیاست سے ریٹائر نہیں ہورہے تو میں قارئین وناظرین کی جند کیوں چھوڑوں۔لکھنے کے شوق کے علاوہ میری مجبوری یہ بھی ہے کہ روز کی روٹی روز کمانے کی مشقت میں اسیر مزدوروں جیسا ہوں۔ لکھوں یا بولوں گا نہیں تو زندہ کیسے رہوں گا؟
اس اعتراف کی وجہ سے آپ میں سے اکثر کے ذہن میں یہ سوال امڈ سکتا ہے کسی فرد کی محض رزق کمانے کی خاطر لکھی تحریر کیوں برداشت کی جائے۔ اس کالم میں کچھ تو اچھوتی بات ہو۔ زبان وبیان کے ہنر سے محروم گزرے دور کا رپورٹر اگر کوئی تازہ خبر فراہم نہیں کرسکتا تو یادوں کی پٹاری سے ہماری سیاسی تاریخ کے کسی اہم ترین مرحلے یا شخصیت کے بارے میں کوئی ایسا قصہ نکالے جو حیران کردے۔ مجھے خبر نہیں کہ آپ یہ تقاضا کرتے ہیں یا نہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے البتہ اس امر کے بارے میں سوچتے ہوئے گھنٹوں صرف کردیتا ہوں کہ ہفتے کے پانچ دن صبح اٹھتے ہی جو کالم لکھتا ہوں وہ پڑھنے والوں کے کس کام کا۔ مذکورہ سوال کے بوجھ سے گھبرا کر اچانک لکھنا چھوڑ سکتا تھا۔ گزشتہ دو برس کے دوران مگر اس کالم کے تسلسل میں چند بار وقفے آئے تو مہربانوں کی خاطر خواہ تعداد پریشان ہوگئی۔ کئی افراد نے نجانے کیسے اور کہاں سے میرا ٹیلی فون نمبر لے کر رابطہ کیا اور میری غیر حاضری کے بارے میں پرخلوص فکر مندی کا اظہار بھی۔ اخبار میں چھپے کالم کواگر ’نوائے وقت‘ کے نیٹ ایڈیشن پر پوسٹ کرنے میں تاخیر ہوجائے تب بھی قارئین کی جی کو حوصلہ دینے والی تعداد مضطرب ہوجاتی ہے۔ ان مہربانوں کی وجہ سے اس گماں میں مبتلا ہوں کہ قارئین کا ایک مخصوص گروہ ہے جو میری یاوہ گوئی کا انتظار کرتا ہے۔ ان کی محبت کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے قابل ہوا تب بھی گوشہ نشین نہیں ہوپائوں گا۔
یہ عرض گزارنے کے بعد اطلاع اگرچہ یہ دینی ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ خیال ستائے چلاجارہا ہے کہ اس کالم کا عنوان بدل دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب دینے سے قبل یہ بیان کرنا لازمی ہے کہ مجھے اردو میں کالم نویسی کی راہ پر مرحوم عباس اطہر صاحب نے تقریباً دھکیلتے ہوئے ڈالا تھا۔ ان کے حکم سے قبل صحافتی عمر کے 25 برس میں نے انگریزی اخبارات کے لیے رپورٹنگ کی تھی اور بعدازاں ان ہی کے لیے کالم لکھنا بھی شروع کردیے۔ میرے کالم مگر حالاتِ حاضرہ کی رپورٹنگ اور ان پر تبصرہ آرائی تک محدود ہوا کرتے تھے۔ اشاروں کنایوں میں تاہم کسی حکومت کے خلاف لگائی گیم کا بروقت بھی ذکر کردیتا اور اس کے تناظر میں ہوئی محلاتی سازشوں کا چسکا فروشوں کی طرح سراغ لگانے میں مصروف رہتا۔ اردو زبان پر لیکن ایسی گرفت میسر نہیں جومحلاتی سازشوں کو بچ بچا کربیان کرسکے۔ اچھے دنوں میں ہمارے حکمران ویسے بھی انگریزی اخباروں کے لیے لکھے کالموں کے بارے میں ’کشادہ دلی‘ کے ڈرامے رچاتے تھے۔غیر ملکی سفارت کاروں یا حکومتوں کے لیے انگریزی زبان میں ہوئی ’گستاخیاں‘ جنرل ضیاء اور پرویز مشرف کی حکومتوں کے ایک حوالے سے بہت کام آئیں۔ جنرل ضیاء اکثر کئی انگریزی کالموں کے حوالے دے کر غیر ملکی مہمانوں کو ہنستے مسکراتے قائل کردیتے کہ وہ فوجی آمر ہونے کے باوجود صحافیوں کی تنقید کھلے دل سے برداشت کرتے ہیں۔
مرحوم عباس اطہر صاحب سے اصرار کرتا رہا کہ 1990ء کی دہائی میں آئی اور گئی نام نہاد ’جمہوری‘ حکومتوں نے سرکار مائی باپ کو بہت نازک مزاج بنادیا ہے۔ محترمہ بے نظیربھٹو اگرچہ بڑے دل کی مالک تھیں۔ نواز شریف مگر اس دہائی میں اپنی حکمرانی کے دونوں ادوار کے دوران ’گستاخیوں‘ کے شاکی ہی رہے۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ٹائپ افسرودرباری اس رویے کا فائدہ ا ٹھاتے ہوئے گستاخوں کو رگڑا لگانے میں پہل لینے کو بے قرار رہتے۔
وقت کا ’حسین ستم‘ مگر یہ بھی ہوا کہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دونوں ادوار کے دوران ایوان ہائے اقتدار میں معتوب ٹھہرایا یہ بدنصیب 2014ء کے برس ان صحافیوں کی فہرست میں پھینک دیا گیا جو شریف خاندان سے ’لفافہ‘ لینے کے عادی بتائے گئے۔ مفت کی بدنامی ہوگئی تو عمران حکومت کے آخری ایام میں ٹی وی سکرینوں سے غائب کیے جانے کے باوجود ایک ’آڈیو لیک‘ ہوئی۔ اس نے مجھے ’ٹوکری لینے والا بابا‘ بھی مشہور کردیا۔ ربّ کا صدشکر کہ اس نے ڈھیٹ ہڈی عنایت کررکھی ہے۔ اس کی بدولت اگر کچھ دن سوشل میڈیا پر ’لفافہ‘ یا ’ٹوکری والا صحافی‘ ہونے کے طعنے نہ ملیں تو جی اداس ہوجاتا ہے۔
بہرحال ذکر ہورہا تھا اس کالم کے عنوان کا۔ دیانتداری سے عرض کررہاہوں کہ اندھی نفرت وعقیدت کے ’کا ل یگ‘ کی طرح طویل تر ہوتے دور میں برملا بات کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔عمر کے آخری حصے میں اگرچہ اس کی بدولت دریافت کررہا ہوں کہ اردو کو ’ادبی‘ زبان بنانے والے فارسی زبان کے کلاسکی شاعری استعاروں کے محتاج کیوں رہا کرتے تھے۔ دورِ حاضر میں اردو کے فیض احمد فیض جیسے ’انقلابی‘ شاعروں کو بھی نظربظاہر وطن کا حال بیان کرنے کے بجائے ’قفس‘ میں گرفتاردلوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔صحافت مگر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کا نام نہیں۔ حقائق اس میں سادہ اور واضح الفاظ میں بیان کرنا ہوتے ہیں اور 2014ء سے شاعری کے محبوب کی کمر جیسی ’جمہوریت‘ جو ’ہے کہ نہیں ہے‘خیالات کا برملا اظہار برداشت ہی نہیں کرسکتی۔ بہت سے موضوعات پر بہت کچھ جاننے کے باوجود میری ’بکل‘ میں چھپے بزدل کو انھیں بیان کرنے کا حوصلہ نہیں۔ آسان ترین راستہ اِن دنوں لہٰذا اس سوال کی مسلسل جگالی کرنا رہ گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید ہوئے عمرن خان کے ’اُن‘ سے رابطے ہورہے ہیں یا نہیں۔
عاشقانِ عمران کو خوش رکھنا ہوتو ’رابطوں اور ملاقاتوں‘ کی ’تصدیق‘ ڈھونڈلینے کا ناٹک لگائیں۔ وگرنہ ان کے امکانات کو عقل کل کی ڈھٹائی سے رد کرتے ہوئے قارئین کے اس حلقے کو مطمئن رکھنے کی کوشش کیجیے جنھیں ’فسطائی‘ عمران خان کی حکومت میں واپسی سے خوف آتا ہے۔ مذکورہ موضوع کی جگالی مگر کتنے روز برقرار رکھی جاسکتی ہے؟ اس کی بابت سوچتے ہوئے ذہن مفلوج محسوس ہونا شروع ہوگیا ہے۔ حقائق ’برملا‘ بیان کرنے کا حوصلہ نہیں تو اس کالم کی چھابڑی میں کیا رکھاجائے۔ اس سوال کے بارے میں مسلسل سوچ رہاہوں۔ آپ بھی خدارا کوئی راہ ڈھونڈنے میں مدد فرمائیں۔
Sunday, November 24, 2024
سوشل میڈیائی فدائیوں کے ریٹائرمنٹ کے مشورے

اسرائیلی وزیراعظم، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں اختلافات
Nov 24, 2024 | 20:19
پہلا ون ڈے : زمبابوے نے پاکستان کو شکست دے دی
Nov 24, 2024 | 20:06
یہ چاہتے ہیں صرف ان سے ڈیل کی جائے اور انہیں این آر او دیا جائے:عطا تارڑ
Nov 24, 2024 | 19:21
-
بیلا روس کا 75 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا، صدر کل آئیں گے
-
بیلا روس کا 75 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا، صدر کل آئیں گے
-
محسن نقوی کا اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ
-
ریاست فسادیوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی: عظمیٰ بخاری
-
راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں جھڑپیں، پولیس کی شیلنگ
-
اسلام آباد کے تمام تعلیمی ادارے کل بند ہوں گے: ضلعی انتظامیہ
ای پیپر دی نیشن
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
عوام کو ریلیف دے کر ہی خانہ جنگی کا راستہ روکا جاسکتا ہے
-
مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے
-
موجودہ حالات ملک میں فوری انتخابات کے متقاضی ہیں
-
بجلی کے بعد پٹرول بم مجبور عوام جائیں تو جائیں کہاں
مفت مشورے
Nov 24, 2024
پاکستان میں دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوتی
Nov 24, 2024
ظہور عالم شہید
Nov 24, 2024
صحت کے میدان میں حکومتی اور انفرادی کاوشیں
Nov 24, 2024
کتاب دوستی اور کتاب دشمنی
Nov 24, 2024
فتوی ساز فون ہیکرزاور درپیش ایشوز پر متحرک کیوںنہیں ہوتے؟
Nov 24, 2024
ٹی ٹاک …طلعت عباس خان ایڈووکیٹ takhan_column@hotmail.com وی پی این ( ورچوئل پرائیوٹ نیٹ ورک) کے استعمال کو اسلامی نظریاتی کونسل نے ...
24 نومبر کال کا اعلان اور حکومتی اقدامات
Nov 24, 2024
پاک فضائیہ… عظمتوں و سیادتوں کی داستان
Nov 24, 2024
سرکاری اسپتالوں کا ایمرجنسی اسٹاف قابلِ تعریف ہے
Nov 23, 2024
اتوار‘ 21 جمادی الاول 1446ھ ‘ 24 نومبر2024
Nov 24, 2024
24ہفتہ ‘ 20 جمادی الاول 1446ھ ‘ 23 نومبر2024
Nov 23, 2024
جمعۃ المبارک ‘ 19 جمادی الاول 1446ھ ‘ 22 نومبر2024ء
Nov 22, 2024
جمعرات،18جمادی الاول 1446ھ 21 نومبر 2024
Nov 21, 2024
بدھ‘ 17 جمادی الاول 1446ھ ‘ 20 نومبر2024
Nov 20, 2024
دنیا سے بے رغبتی
Nov 24, 2024
فضائل و بر کات نام محمد(۲)
Nov 23, 2024
فضائل و بر کات نام محمد ﷺ(۱)
Nov 22, 2024
معاشی خود انحصاری (2)
Nov 21, 2024
معاشی خود انحصاری (۱)
Nov 20, 2024
فرمان قائد
Nov 24, 2024
جلسہ عام ڈھاکہ 28 مارچ 1948
Nov 24, 2024
فرمان قائد
Nov 23, 2024
بحریہ پاکستان سے خطاب 23 جنوری 1948ء
Nov 23, 2024
ڈھاکہ … 31 مارچ 1948ء
Nov 22, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 24, 2024
ضربِ کلیم
Nov 24, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 23, 2024
بانگِ درا
Nov 23, 2024
ضربِ کلیم
Nov 22, 2024
نیوز لیٹر سبسکرپشن
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 41
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Invalid argument supplied for foreach()
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 42
اشتہار
رابطہ

NIPCO House, 4 - Shaharah e Fatima Jinnah
Lahore Pakistan
Tel: +92 42 36367580 | Fax : +92 42 36367005
Nawaiwaqt Group | Copyright © 2024