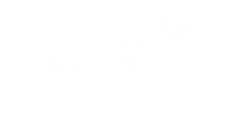ادھ کھلی آنکھوں پر جب نیند کا سرمئی غبار پھیلنے لگتا تو جیسے گاﺅں کے چرواہے بابا نیاز علی کی اچھلتی کودتی اتھری بھیڑوں کا ریوڑ بادلوں کے سفید گالوں میں ڈھل کر خانہ¿ چشم پر چادر تان دیتا۔ ہلکورے لیتے ڈوبتے ذہن میں اسی صبح مدرسے میں ہر جماعت غضنفر کی گائی مناجات خوشبو کی طرح در آتی:
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری
ہر صبح مدرسے میں گائی اور ہر شب یونہی آنکھوں میں نیند بن کر اترتی نظم مشعل راہ بنتی گئی اور میں اقبال کا مقروض ہوتا گیا۔
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا
درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا
ہو میرے دم سے یونہی میرے وطن کی زینت
جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت
پھر نصف دہائی گزری۔ نویں جماعت میں ایک مختلف اقبال کا سامنا ہوا۔ ہمارے اردو کے استاد قاضی عبدالرحمن عاشق اقبال تھے۔ اپنا مرض ساری جماعت کو لگاتے پھرے۔
روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل
آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر
جاوید منزل میں چارپائی پر بیٹھے ایسا الہامی کلام لکھنے والے مرد قلندر کا میں اور مقروض ہوگیا۔ وہ جو میری زندگی کو ڈھب پر لا رہا تھا اس کا قرض میں کیسے چکا سکوں گا؟ماہ و سال گزرے اور قدموں تلے آنے والی خاک مختلف موسموں میں اپنی طرف کھینچتی رہی۔ اڑھائی دہائیاں پیشتر کے جشن نو روز میں شہر شیراز پر ایک خمار آلودہ سرمئی شام اتر رہی تھی۔ باد شمیم بہار کے استقبال میں رقص کرتی تھی اور حافظ شیرازی کے مزار پر موتیے اور یاسمین کی خوشبو سرگرداں تھی۔ احاطے میں ایرانی مرد و زن بیٹھے دیوان حافظ پڑھتے تھے۔ کچھ چادر پوش دوشیزائیں آنکھوں میں آرزوﺅں کی مشعلیں روشن کئے دیوان سے فال نکالنے میں لگی تھیں۔ میں خاموشی سے منقش قبر کے کتبے کے پاس جا بیٹھا۔ قبر اور لوح پر کندہ کئی اشعار تھے۔ ایک جگر پر ہاتھ ڈالتا تھا:
وجود ما معما ئیست حافظ
کہ تحقیقش فسون است و فسانہ
(اے حافظ! ہمارا وجود ایک معما ہے کہ جس کی تحقیق کئی اور معموں اور افسانوں میں الجھا دے گی)
میرے دائیں ہاتھ بیٹھے سفید ریش ایرانی بزرنگ نے دیوان حافظ سے سر اٹھایا اور سرگوشی میں مجھ سے مخاطب ہوا ”آقای! شما از کجا ہستید؟ (آپ کہاں سے ہیں؟)
”پاکستانی ام“ میرا جواب مختصر تھا۔
”اقبال لاہوری رامی شنا سید؟“ (کیا آپ اقبال لاہوری کو جانتے ہیں؟) اس کی سرگوشی تیز ہوگئی۔
”نہ خیر۔ممکن است در لاہور بیشتر از صد ہزار اقبال زندگی می کُنند“ (نہیں میں نہیں جانتا۔ ہوسکتا ہے کہ لاہور میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ اقبال رہائش پذیر ہوں) میں نے لاپروائی سے کہا۔
ایرانی کی آنکھوں میں جیسے چراغوں کی کہکشاں اتری۔ اپنا رعشہ زدہ ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر بڑی عقیدت سے بولا ”اما اقبال لاہوری فقط یک است۔ نہ شنیدی آں مرد قلندر چہ گفت؟
نہ بہ امروز اسیرم نہ بہ فردا نہ بہ دوش
نہ نشیبے نہ فرازے نہ حقامے دارم
(نہ میں آج میں مقید ہوں اور نہ آنے والے کل یا گزرے کل میں اسیر ہوں۔ کوئی منزل یا مقام میرے راستے میں حائل نہیں ہے)
تب جیسے موتیے اور یاسمین کی نکہت نے اڑان سمیٹی اور اس سکوت میں مجھے اس حافظ کی یاد آئی جو راوی کے کنارے ردائے خاک اوڑھے لیٹا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب عالم اسلام اس کے کہے حرف کا قرض چکائے گا۔ مزار حافظ پر یاد اقبال کا چراغ جلانا بھی ایک پرلطف تجربہ تھا۔ پھر شیراز بھی گرد راہ ہوا۔
ایک اور نصف دہائی تاریخ بنی۔ 80ءکی دہائی کے ابتدائی برسوں کی بات ہے۔ سعودی ٹیلی وژن کے سٹوڈیو B میں روشنیوں کا ہالہ تھا اور میرے سامنے ایک حقیقت شناس ہستی تھی۔ بیسویں صدی کی عظیم ترین مستشرق اوراقبالیات کی ماہر جرمن پروفیسر این میری شمل کو میں نے انٹرویو کرناتھا۔ میں نے بات چھیڑی۔ پھر کسی سوال کی حاجت نہ رہی۔ ہیگل سے بات کا آغاز انہوں نے کیا۔ فرانسیسی فلسفی برگساں کے تصور وقت اور حرکت کائنات کا بھی ذکر ہوا۔ برطانوی برٹرینڈرسل کی UTILITARIANISM کی ڈاکٹرائن کا انہوں نے تجزیہ کیا لیکن بات جب اقبال پر پہنچی تو جہاندیدہ مہربان آنکھوں میں چراغاں کی کیفیت تھی۔ بولیں ”مغربی فلسفہ سارے کا سارا تہی دست ہے۔ ہر ایک اپنی سوچ کا محور صرف انسان کو ہی بناتا ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی کسی کو توفیق ہی نہیں۔ لیکن اقبال کے ہاں ایک اور بھی ہے انسان سے بھی بڑا جس کے ہاں آخری دربار لگتا ہے پھر انہوں نے حکیم الامت کا یہ شعر پڑھا:
فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا
یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک
تب سٹوڈیو B کی درجنوں روشنیوں کے سیلاب میں بہتے مجھے ایک بار پھر بڑی شدت سے اس حقیقت کا احساس ہوا تھا کہ میں اپنا ادھار چکانے کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہا۔این میری شمل کی آنکھوں اور ان کے لبوں سے نکلی بات بھی لقمہ¿ نسیان ہوگئی۔ وقت کے غبار میں دھندلا گئی۔
پھر پانچ برس پیشتر کہ ایک غروب آفتاب سے قبل میں نے اپنے آپ کو لاہور کے ایوان اقبال میں اقبالیات کے ماہر جاوید احمد کے سامنے بیٹھا پایا۔ سعودی ریڈیو کی اردو سروس کے لئے انٹرویو مقصود تھا اور آخری مترد و سوال بھی پوچھ ڈالا ”آج اقبال کو غیر مربوط کیوں بنایا جا رہا ہے؟“
عالم کی سفید ریش آہستہ آہستہ جھکتی سینے پر جا پھیلی۔ ایک طویل سکوت تھا لیکن میں نے وہ بے صدا آواز سن لی تھی۔ اس میں امن کی بے چارگی، شرمندگی اور درماندگی کے نوحے تھے۔ غروب آفتاب کا عمل تھا۔ تاریکی پر پھیلائے منتظر تھی اور پھر گزشتہ ہفتے ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے ایک بار پھر شدید اندیشہ¿ زیاں میں مبتلا کر دیا۔ میرے بارہ سالہ بیٹے نے مجھ سے لفظ شاہین کے معنی پوچھے۔ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ انگریزی بہت اچھی لکھتا اور بولتا ہے کہ آج کل کی تعلیم کا یہی چلن ہے۔ اسے فرانسیسی سے بھی شدبد ہے۔ اردو بھی جتنی پاکستانی دفاتر میں استعمال ہوتی ہے جانتا ہے لیکن اس کا المیہ بھی وہی ہے جو ہماری ساری قوم کا ہے۔ وہ اپنی راہ گم کر رہا ہے۔ نشان منزل کھو چکا ہے۔ شاہین کے معنی نہیں جانتا۔ خودی کا مفہوم نہیں سمجھتا۔ مرد مومن کے الفاظ اس کے لئے اجنبی ہیں اور میں ہوںکہ ابھی تک اپنا قرض ہی نہیں لوٹا سکا۔
9نومبر کی صبح مجھے خیال آتا ہے کہ آج تو یوم اقبال ہے۔ ایک مختصر سی تقریب میں بادل نخواستہ جاتا ہوں۔ مدارس کے چند ایک بچے جمع ہوتے ہیں۔ چند لکھی ہوئی تقاریر پڑھی جاتی ہیں مزار اقبال پر چادر چڑھتی ہے اور بس۔
یاد اقبال بھی مزار اقبال پر چڑھائے پھولوں کی مہک کی طرح ہواﺅں کے دوش پر تیرتی ہلکی پڑتی ماضی کے حاشیے میں جا سوتی ہے۔ اب کسی معصوم کے نیم خوابیدہ ذہن میں ”لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری“ کی گنگناہٹ نہیں تیرتی۔ اب کوئی استاد بچوں کو عشق اقبال میں مبتلا نہیں کرتا اور منزل کے لئے بھٹکتی ایک قوم ہے کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ ایک مرد درویش کی مقروض سے مقروض تر ہوتی جا رہی ہے۔
سر آمد روز گارے ایں فقیرے
دگر دانائے راز آید کہ ناید
Tuesday, November 19, 2024
مقروض قوم
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری
Nov 19, 2024 | 18:58
پاکستان: سونے کی قیمت میں اچانک بڑی تبدیلی
Nov 19, 2024 | 18:05
پی ٹی آئی کا احتجاج،وزارت داخلہ کا سخت ترین اقدامات کا فیصلہ
Nov 19, 2024 | 18:00
دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024، کراچی میں دفعہ 144 نافذ
Nov 19, 2024 | 17:56
-
وزیراعلیٰ پنجاب کا طلبہ کیلئے ہونہار سکالرشپ پروگرام کا اعلان
-
وزیراعلیٰ پنجاب کا طلبہ کیلئے ہونہار سکالرشپ پروگرام کا اعلان
-
پاکستان اسٹاک مارکیٹ : ہنڈرڈ انڈیکس تاریخ کی نئی بلندیوں کو ...
-
لبنان، غزہ اور شام کے متاثرین کے لیے 20 ویں امدادی کھیپ روانہ
-
تھائی لینڈ: 200 بندروں کی غنڈہ گردی، پولیس بھی ڈر گئی
-
آئیڈیاز 2024: پاکستان کی بڑی کامیابی، جدید لڑاکا ڈرون شاہپر تھری ...
ای پیپر دی نیشن
معیشت میں بہتری کے دعوے اور عوام کی حالتِ زار
Nov 19, 2024
پی ٹی آئی کا اسلام آباد پر دھاوا بولنے کا منصوبہ
Nov 19, 2024
دھی رانی اورمعذور وں کی بحالی کے پروگرام
Nov 18, 2024
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
عوام کو ریلیف دے کر ہی خانہ جنگی کا راستہ روکا جاسکتا ہے
-
مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے
-
موجودہ حالات ملک میں فوری انتخابات کے متقاضی ہیں
-
بجلی کے بعد پٹرول بم مجبور عوام جائیں تو جائیں کہاں
باس اور لیڈر
Nov 19, 2024
وزیراعلیٰ پنجاب کا دھی رانی پروگرام
Nov 19, 2024
بتوں سے تجھ کو امیدیں۔۔۔
Nov 19, 2024
موسمیاتی قیامت : وزیر اعظم کی عالمی لیڈروں کو وارننگ
Nov 19, 2024
کوئی لاش گرے، کوئی خون بہے، کوئی بات بنے!
Nov 19, 2024
مسلم ممالک کو اتفاق واتحاد کی دعوت
Nov 19, 2024
از۔۔۔ ظہیرالدین بابر وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب میں ہونے والی کانفرس میں جس طرح غزہ میں ڈھائے جانے والی اسرائیل مظالم ...
وی پی این کی بندشاورصارفین کی پرائیویسی
Nov 19, 2024
کیا صدر ٹرمپ اپنے کیے ہوئے وعدے ایفا کر سکیں گے؟
Nov 19, 2024
منگل‘ 16 جمادی الاول 1446ھ ‘ 19 نومبر2024
Nov 19, 2024
پیر‘ 15 جمادی الاول 1446ھ ‘ 18 نومبر2024ء
Nov 18, 2024
اتوار‘ 14 جمادی الاول 1446ھ ‘ 17 نومبر2024
Nov 17, 2024
ہفتہ،13جمادی الاول 1446ھ16نومبر 2024
Nov 16, 2024
جمعۃ المبارک،12جمادی الاول 1446ھ15نومبر 2024
Nov 15, 2024
ماحولیاتی آلودگی(۲)
Nov 19, 2024
ماحولیاتی آلودگی(۱)
Nov 18, 2024
درخت لگانے کے فوائد اور اہمیت
Nov 17, 2024
اسلامی معاشرے کے عوامل (2)
Nov 16, 2024
اسلامی معاشرے کے عوامل (1)
Nov 15, 2024
فرمان قائد
Nov 19, 2024
جلسہ عام ڈھاکہ 21 مارچ 1948
Nov 19, 2024
فرمان قائد
Nov 18, 2024
رائٹر کے نمائندے سے انٹرویو 25 اکتوبر 1947ء
Nov 18, 2024
فرمان قائد چ
Nov 17, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 19, 2024
بالِ جبریل
Nov 19, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 18, 2024
بانگ ِ درا
Nov 18, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 17, 2024
نیوز لیٹر سبسکرپشن
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 41
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Invalid argument supplied for foreach()
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 42
اشتہار
رابطہ

NIPCO House, 4 - Shaharah e Fatima Jinnah
Lahore Pakistan
Tel: +92 42 36367580 | Fax : +92 42 36367005
Nawaiwaqt Group | Copyright © 2024