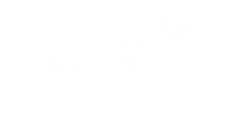ابھی دو دن پہلے مرحوم وارث میر کی 30ویں برسی گزری ہے۔ اس سے ایک ہفتہ قبل ان کے صاحبزادے عامر میر نے اپنی مرتب کردہ ان کی نئی کتاب ”فلسفہ¿ خوشامد“ مجھے بھجوائی تو اس کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر ضیاءکی جرنیلی آمریت سے وابستہ میری اپنی کئی یادیں بھی تازہ ہوگئیں۔ وارث میر بلاشبہ دبنگ دانشور اور بے لاگ کالم نگار تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کے جرنلزم ڈیپارٹمنٹ کے استاد اور پھر سربراہ رہے مگر اپنی اس سرکاری حیثیت کے باوجود نوائے وقت اور پھر جنگ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے قلم کے ذریعے ضیاءآمریت کے مقابل کھڑے نظر آتے رہے۔ میں 1981ءمیں نوائے وقت سے وابستہ ہوا تو وارث میر اس ادارے کے چوٹی کے قلمکاروں میں شمار ہوتے تھے۔ میرا ان سے نیاز مندی کا سلسلہ بھی اس وقت سے ہی شروع ہوا۔ وہ آفس آتے تو ان سے ملاقات بھی ہو جاتی اور پھر اکثر نوائے وقت کے آفس کے باہر چیئرنگ کراس کے بس سٹاپ پر ان سے ملاقات ہونے لگی، جہاں وہ نوائے وقت کے آفس سے نکل کروحدت روڈ کی جانب بس یا ویگن کے انتظار میں کھڑے نظر آتے۔ میں حیران ہوتا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک معتبر ادارے کے سربراہ ہیں مگر بس سٹاپوں پر دھکے کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ درحقیقت یہی ان کے پروفیشنل اور ایماندار ہونے کی دلیل تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے قلم کا رُخ حکمرانوں کی مدح سرائی کی جانب متعین کرکے ان سے بے شمار مراعات لے سکتے تھے مگر انہوں نے ایک استاد، مبلغ اور قلمکار کی حیثیت سے اپنے اجلے دامن پر کبھی کوئی داغ نہ لگنے دیا۔ ان کاشمار بھٹو کے رطب اللسانوں میں بھی ہرگز نہیں ہوتا تھا جبکہ ضیاءآمریت کو انہوں نے اپنے مافی الضمیر کے مطابق چیلنج کرنے کا راستہ اختیار کیا اور حکومتی انتظامی عتاب برداشت کرتے وہ کلمہ¿ حق ادا کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔
اس وقت بھی ضیاءآمریت کے رطب اللسان قلمکاروں، صحافیوں، کالم نگاروں کی ایک پوری کھیپ ان کی کاسہ لیسی اور اس کے صدقے دنیاوی آسائشیں اور مراعات سمیٹنے میں مصروف تھی۔ اخبارات میں پری سنسرشپ اتنی سخت گیر تھی کہ میجر رینک کا ایک فوجی افسر ہر اخبار کے نیوز روم میں آنے والی خبریں اور ادارتی صفحات پرجانے والے مضامین کی مانیٹرنگ کیا کرتا تھا۔ جس خبر، کالم یا مضمون میں ضیاءکی مخالفت کا شائبہ بھی گزر جاتا، اسے یک قلم چاک کردیا جاتا۔ اس طرح کئی اخبارات کے صفحات سنسر کی نذر ہوکر اکثرخالی پرنٹ ہوا کرتے تھے۔ 1977ءمیں مَیں پی این اے کی ایک جماعت تحریک استقلال کے زیر اہتمام اپنی اشاعت نو کا آغاز کرنے والے روزنامہ ”آزاد“ کے ساتھ بطور سٹاف رپورٹر وابستہ ہوا اور کالم نگاری کا آغاز بھی اسی اخبار سے کیا۔ عباس اطہر مرحوم اس اخبار کے ایڈیٹر تھے اور معروف پنجابی شاعر مسعود منور بھی اسی اخبار کے ساتھ وابستہ تھے۔ اخبار کی پالیسی کے مطابق ضیاءآمریت ہمارے ہدف پر تھی اور بھٹو کی گزری سول آمریت پر پھبتیاں کسنا بھی اخبار کی پالیسی میں شامل تھا، جس کے لئے این سی اے کے استاد اور معروف کارٹونسٹ خالد سعید بٹ کی بطور خاص خدمات حاصل کی گئیں۔ ہائی کورٹ میں زیر سماعت بھٹو کیس کی کوریج میری ذمہ داری تھی جس کی تقریباً روزانہ لیڈ سٹوری بنتی اور اخبار کا آخری صفحہ اس خبر کے بقیہ سے ہی بھرا ہوتا۔ خالد سعید بٹ بھی اسی کیس کے حوالے سے کارٹون بناتے جبکہ اخبار کا اداریہ اور اکثر کالم بھی اسی کیس کا احاطہ کیا کرتے تھے چنانچہ مجھے اپنی کالم نگاری کے آغاز ہی میں اپنے ضمیر کے مطابق ضیاءآمریت کی نکاتی کا بھرپور موقع ملنا شروع ہوگیا۔ اسی طرح بھٹو کی سول آمریت بھی میرے ہدف پر رہی جس کا میں زمانہ¿ طالب علمی سے ہی ناقد تھا اور اپنی ایک نظم ”چاہے دیس بھی ہو کنگال، بھٹو جئے ہزاروں سال“ پر قومی شاعر حفیظ جالندھری سے داد بھی سمیٹ چکا تھا۔
1977ءکے اختتام تک تو ”آزاد“ بھٹو اور ضیاءآمریت کی مخالفت کو ساتھ ساتھ چلا کر آگے بڑھتا رہا مگر جب صرف ضیاءآمریت اس اخبار کا ہدف بنی تو اخبار کی یہ آزادی ضیاءآمریت سے برداشت نہ ہوپائی۔ شومئی قسمت اس وقت بھٹو مرحوم کی جیل سے موصول ہونے والی ایک تحریر ”اگر مجھے قتل کیا گیا“ عباس اطہر کے ہتھے چڑھی اور ان سے اس تحریر کو اپنے دوست مظفر الحسن کے پریس سے چھپوا کر تقسیم کرنے کا جرم سرزد ہوگیا۔ چنانچہ وہ دھر لئے گئے اور جیل سے روزانہ فوجی عدالت میں ان کی پیشی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اخبار کے اشتہارات پہلے ہی بند ہوچکے تھے، کرنل مظفر اور پھر محمد سعید اظہر کی ادارت میں اخبار ”پبّاں بھار“ چلنے لگا اور پھر آصف فصیح الدین وردگ کی منیجنگ ایڈیٹری میں یہ اخبار ضیاءآمریت کے جھٹکے کھاتا اپنے اصل مالک کے پاس ڈمی بن کر واپس چلا گیا۔ بیکاری کا عرصہ شروع ہوا تو اس دوران ریڈیو پاکستان پر پروڈیوسر کی آسامی نکلی جس کے لئے میں نے بھی اپلائی کردیا مگر مقررہ دن کمرئہ امتحان کے باہر کھڑے سکیورٹی کے آدمی نے میرا نام پوچھتے ہی مجھے دروازے کے باہر روک لیا۔ اس کی باڈی لینگوئج سے محسوس ہوا جیسے وہ بے تابی کے ساتھ میرا ہی انتظار کررہا تھا۔ کرختگی سے بولا: ”آپ اندر نہیں جاسکتے“۔ میں نے وجہ پوچھی تو مزید کرختگی سے بولا: ”ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ آپ کو امتحان میں نہیں بیٹھنے دینا“۔ میں امتحان میں بیٹھے بغیر واپس چلا آیا۔ بعد میں میری پوچھ تاچھ پر عقدہ کھلا کہ ”آزاد“ میں ضیاءآمریت کے خلاف لکھے میرے کالم میری سرکاری نوکری کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں جس کے لئے درخواست فارم پر درج میرا نام ہی کافی تھا۔ اس طرح مجھے 1984ءمیں بھی ضیاءآمریت کے جبری ہتھکنڈوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں لاہور پریس کلب کا سیکرٹری تھا اور میں نے ”تجزیہ“ پروگرام کے تحت ضیاءآمریت کے مخالف ایم آر ڈی کے قائدین کو پریس کلب کے پلیٹ فارم پر مدعو کرنے کا سلسلہ شروع کررکھا تھا، اس وقت لاہور ہائیکورٹ بار اور لاہور پریس کلب کے دو ہی ایسے پلیٹ فارم تھے جہاں پر حکومت مخالفین کو عوام تک اپنا مو¿قف پہنچانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے ایک پروگرام میں ہائیکورٹ بار کے اس وقت کے صدر سید افضل حیدر کو مدعو کیا تو ایک خفیہ والا پلندے کی شکل میں موجود ایک فائل اٹھائے میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ پریس کلب میں حکومتی مخالفین کو مدعو کرنا بند کردیںورنہ اس فائل میں آپ کے خلاف اتنا مواد موجود ہے کہ آپ کو آزادی¿ صحافت کا مفہوم سمجھ آجائے گا۔ میں نے اس دھمکی کو قطعاً درخوراعتناءنہ سمجھا اور تجزیہ پروگرام جاری رکھا۔ اگرچہ خفیہ والے تواتر کے ساتھ مجھے ڈراتے دھمکاتے رہے۔
اس حوالے سے میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں کہ مرحوم وارث میر کو ضیاءآمریت کے خلاف سرکاری ملازم کی حیثیت سے لکھنے کے باعث کس ذہنی کرب و اذیت سے گزرنا پڑا ہوگا۔ ان کے صاحبزادوں حامد میر اور عامر میر نے اپنے والد مرحوم کے اس کرب کا تذکرہ کیا ہے جبکہ کتاب میں موجود وارث میر کے نوائے وقت اور جنگ میں شائع شدہ کالموں میں بھی ضیاءآمریت کے سامنے کلمہ¿ حق کہنے والی ان کی ”گستاخیوں“ کی جھلکیاں بکھری پڑی ہیں۔ اپنا آخری کالم جو ان کی وفات کے اگلے روز شائع ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے عامر میر کو ڈکٹیٹ کرایا تھا جو یقینا عامر میر کے لئے ایک اعزاز بن چکا ہے۔ عامر میر نے اپنے والد مرحوم کے نوائے وقت سے جنگ میں جانے کا جو پس منظر بتایا ہے، میرا یقین ہے کہ وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ مرحوم مجیدنظامی کسی بھی مضمون یا کالم کو اشاعت سے بمشکل ہی روکا کرتے تھے۔ جب مجھے انہوں نے شعبہ ادارت کی ذمہ داری تفویض کی تو بطور خاص یہ ہدایت کی کہ کسی کالم یا مضمون کو اشاعت سے روکنے سے ہرممکن گریز کریں، کوئی کالم ادارے کی پالیسی کے منافی ہو تو اسے مناسب ایڈٹ کرکے اشاعت کے قابل بنا لیا جائے مگر کسی کا کالم روکا جائے گا تو اس سے لکھنے والے کی دل آزاری ہوگی۔ میں نے آج تک ان کی یہ بات پلے باندھی ہوئی ہے۔ خود میرے دو کالم ایسے ہیں جن کی اشاعت کے ہفتے دو ہفتے بعد مجید نظامی صاحب نے کسی اور موضوع پر بات چیت کے دوران مجھے بتایا کہ ان کالموں کی اشاعت کے بعد آپ کا کالم بند کرانے کے لئے مجھ پر وفاقی حکومت کے مخصوص حلقے کی جانب سے بہت دباﺅ آیا تھا مگر میں نے انہیں واضح کردیا کہ آپ مجھ سے ایسی کوئی توقع نہ رکھیں۔ پھر انہوں نے مجھے معنی خیز لہجے کے ساتھ مشورہ دیا کہ آپ تھوڑا سا ”ہتھ ہولا“ رکھا کریں۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ میرے ایسے ہی لکھتے رہنے کی حوصلہ افزائی کررہے ہوں۔ اس لئے میرے یہ گمان میں بھی نہیں آسکتا کہ مجید نظامی صاحب نے وارث میر کا کوئی کالم اشاعت سے روکا ہوگا۔ وارث میر کے نوائے وقت کو خیرباد کہنے کا جو بھی پس منظر ہو، میں اس بات کا بہرصورت معترف ہوں کہ وہ مزاحمتی قلمکار تھے جو سلگتے ایشوز پر قوم کو گائیڈ لائن فراہم کرنے کی حتیٰ الوسع کوشش کرتے رہے اور اسی جہد مسلسل میں انہوں نے محض 47 سال کی عمر میں اپنی جان جانِ آفریں کے سپرد کردی۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔
عامر میر کی مرتب کردہ ان کی کتاب ”فلسفہ¿ چاپلوسی“ موضوع کے اعتبار سے ہمارے آج کے حالات پر بھی منطبق ہوتی ہے کیونکہ آج پانامہ کیس کے حوالے سے ہمارے کئی معتبر کالم نگار فلسفہ¿ چاپلوسی کے مکمل اسیر ہوچکے ہیں۔ ہمارے دوست عرفان صدیقی نے تو کالم نگاری چھوڑ کر اپنا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا مگر ہمارے قلم قبیلے میں آج فلسفہ¿ چاپلوسی ڈنکے کی چوٹ پر اپناآپ منوا رہا ہے۔ سو اس فلسفے کو اجاگر کرنے والے مرحوم وارث میر بھی آج زیادہ شدت سے یاد آرہے ہیں۔ عامر میر بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم کے مخصوص موضوعات پر مبنی کالموں کو کتاب کی شکل میں مرتب کرکے شائع کرانے کے صحیح وقت کا انتخاب کیا ہے۔
Monday, November 25, 2024
وارث میر کا ”فلسفہ چاپلوسی“ اور میری یادداشتیں

پنجاب: بیکار زمینوں پر جنگل لگانے کا فیصلہ
Nov 25, 2024
شیطانی وسوسے اور ان کا حل (۱)
Nov 25, 2024
پیر‘ 22 جمادی الاول 1446ھ ‘ 25 نومبر2024ء
Nov 25, 2024
ای پیپر دی نیشن
ضلع کرم: جھڑپوں میں شدت، اموات میں اضافہ
Nov 25, 2024
پنجاب: بیکار زمینوں پر جنگل لگانے کا فیصلہ
Nov 25, 2024
آرمی چیف کا دہشتگردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ
Nov 24, 2024
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
عوام کو ریلیف دے کر ہی خانہ جنگی کا راستہ روکا جاسکتا ہے
-
مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے
-
موجودہ حالات ملک میں فوری انتخابات کے متقاضی ہیں
-
بجلی کے بعد پٹرول بم مجبور عوام جائیں تو جائیں کہاں
ہم دہشت گردی ختم کیوں نہیں کرسکے؟
Nov 25, 2024
قاری ہوں، لکھنا میری پہلی ترجیح نہیں
Nov 25, 2024
قصہ ایک بھارتی جاسوسہ کا!
Nov 25, 2024
صوفیہ بیدار کی کتاب ’’رنگریز‘‘
Nov 25, 2024
تعلیم کی اہمیت اور ہمارے رویے
Nov 25, 2024
پی آئی اے ’’ کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائوں ‘‘
Nov 25, 2024
پاکستانی معیشت، سیاست، سماج، قومی اداروں کے زوال بر بادی میں حکمراں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان کی عالمی برادری میں وقارصرف ...
ہماری عزتِ نفس کی بحالی: کردار سازی کی فوری ضرورت
Nov 25, 2024
بہترین کارکردگی میں پنجاب ڈینٹل ہسپتال لاہور
Nov 25, 2024
اتوار‘ 21 جمادی الاول 1446ھ ‘ 24 نومبر2024
Nov 24, 2024
24ہفتہ ‘ 20 جمادی الاول 1446ھ ‘ 23 نومبر2024
Nov 23, 2024
جمعۃ المبارک ‘ 19 جمادی الاول 1446ھ ‘ 22 نومبر2024ء
Nov 22, 2024
جمعرات،18جمادی الاول 1446ھ 21 نومبر 2024
Nov 21, 2024
بدھ‘ 17 جمادی الاول 1446ھ ‘ 20 نومبر2024
Nov 20, 2024
شیطانی وسوسے اور ان کا حل (۱)
Nov 25, 2024
دنیا سے بے رغبتی
Nov 24, 2024
فضائل و بر کات نام محمد(۲)
Nov 23, 2024
فضائل و بر کات نام محمد ﷺ(۱)
Nov 22, 2024
معاشی خود انحصاری (2)
Nov 21, 2024
پیر‘ 22 جمادی الاول 1446ھ ‘ 25 نومبر2024ء
Nov 25, 2024
خطبہ صدارت دستور ساز اسمبلی پاکستان 11 اگست 1947ء
Nov 25, 2024
فرمان قائد
Nov 25, 2024
فرمان قائد
Nov 24, 2024
جلسہ عام ڈھاکہ 28 مارچ 1948
Nov 24, 2024
ارمغانِ حجاز
Nov 25, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 25, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 24, 2024
ضربِ کلیم
Nov 24, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 23, 2024
نیوز لیٹر سبسکرپشن
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 41
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Invalid argument supplied for foreach()
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 42
اشتہار
رابطہ

NIPCO House, 4 - Shaharah e Fatima Jinnah
Lahore Pakistan
Tel: +92 42 36367580 | Fax : +92 42 36367005
Nawaiwaqt Group | Copyright © 2024