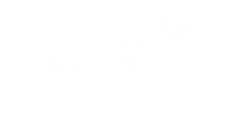وہ صبح ہم نے استنبول میں کی اور آنکھیں ملتے ہوئے استقلال جادہ سی (استقلال اسٹریٹ) جا پہنچے۔اب کی بار میرے ساتھ کچھ دوست ایسے بھی تھے جنھیں پہلی بار اس دیار میں آنے کا موقع ملا تھا۔ان میں سے ایک نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا:
’’ ہمیں کچھ ایسا دکھاؤ کہ زندگی بھر یاد رہے‘‘۔
سامنے ٹرام کی پٹڑی تھی، میں نے احتیاط سے اسے عبور کیا اور ’’لقم‘‘ یعنی ٹرکش ڈیلائٹ کی بھری پری دکان کے سامنے کھڑا ہوکر لحظہ بھرسوچا اور پھر انھیں لیے عظیم الشان قدیمی’’ کلی سے‘‘ یعنی چرچ کی دیوار سے لگا لگا آگے بڑھ گیا جہاں بے فکروں کی ٹولی اپنے ڈھول تاشے سنبھالے ترک تانیں بلند کررہے تھے اور نیم دائرے کی شکل میں محو رقص تھے۔انھوںنے ہم مسافروں کو دیکھا، سینے پر چمکتے ہوئے سبز ہلالی پرچم پر پیار بھری نگاہ ڈالی اور دائیں بائیں سے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا ، پھر نرمی سے ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ رقص میں شمولیت کی دعوت دی۔ اب استقلال جادہ سی پر پاکستانی دھمال اورترک ہلائے (HALAY)نے مل کر وہ سماں باندھا کہ فضا تالیوں سے گونج اٹھی۔ میرے دوست نہال ہوگئے۔
رقص ختم ہوا تو میزبان رقاصوں کے ساتھ آدھی، پونی اور پوری پوری جپھیاںڈال کر خوشی سے لبالب بھرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس خوب صورت شاہراہ پر مٹر گشت کرنے والے بے فکروں کے ہجوم میں شامل ہوگئے۔اس دورا ن ایک دوست نے میرے اور احمد کے درمیان گردن ڈال کر کان میں کہا کہ کچھ اور۔اسی لمحے میری نگاہ ڈون ڈرما یعنی آئس کریم والے پر پڑی۔ اس شہر کے آئس کریم والے بھی خوب ہیں، سیاہ پھندنے والی سرخ روایتی ترکی ٹوپی، سنہری دھاریوں والا سرخ کوٹ اور بالٹی میںگھوٹا لگا کر لمبا سا کفگیر برق رفتاری سے گھنٹی بجا نے اور اس سے گاہک کو چونکا دینے والے۔ خریدار ابھی گھنٹی کی گونج سے نکل نہیں پاتاکہ وہ اپنے کفگیرسے ڈون ڈرما کو اس کی طرف بڑھاتا ہے لیکن خریدار جیسے ہی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے، ڈون ڈرما اس کے گالوں تک جا پہنچتی ہے۔ہاتھ چہرے تک پہنچتے ہیں تو آئس کریم لپک کر پیٹ کو جا چھوتی ہے لیکن پکڑائی میں یہاں بھی نہیں آتی ،وہ دائیں بائیں کانوں کو چھوتے، ماتھے کا بوسا لیتے کہیں کی کہیں جا پہنچتی ہے۔میرے دوست اس تجربے سے بھی محظوظ ہوئے لیکن میری نگاہ تو ایک تصویر میں اٹکی ہوئی تھی۔ ترک بہت گہرے ہوتے ہیں، اپنی دکان مکان کو سستی اشتہار بازی سے نہیں چمکاتے لیکن یہ معاملہ کچھ مختلف تھا۔یہ منظر شاید باسفورس برج کا تھا جس پر ٹینکوں کی ایک طویل قطار کے سامنے لوگوں کا ہجوم نعرہ زن تھا۔ ان میں ایک نوجوان نمایا ں تھا، میں نے غور سے دیکھا تو اس کی شباہت آئس کریم والے سے ملتی جلتی دکھائی دی۔ مداری کی طرح تماشا دکھاتے ہوئے ڈون ڈرماوالے کی تیز نگاہوں سے میری محویت چھپ نہ سکی۔اُس نے ایک پیار بھری مسکراہٹ میری طرف اچھال کر آنکھ ماری تو اپنے ساتھیوں کو آگے روانہ کرکے میں وہیں رک گیا جب ذرا س کے گاہکوں کا ہجوم چھٹا تو میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یہ تصویر کیسی ہے؟ ’’ویسی ہی ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو‘‘۔
اس نے مختصر جواب دیا تو میں نے کہا کہ پھر بھی؟اب اس کا مسخرہ پن ختم ہوا اوراس نے نرم میٹھے لہجے میں بتایا کہ اون بیش تین موز کی ہے یعنی 15؍ جولائی کی ہے۔’’ تم تو ایک مزدور آدمی ہو، تمھارا سیاست کے جھمیلوں سے کیا لینا دینا؟‘‘۔
’’ اُس روز میں کوئی تنہا تو اس ہجوم میں شامل نہ تھا، یہ پڑوس کا احمت فاروک بھی تھا،اس نے اس بازار میں بکنے والے آلو کے معروف پکوان والے کے علاوہ بعض دیگر دکان داروں کی طرف بھی اشارہ کیا۔میں نے اس کی بات ذہن میں بٹھا لی اور آگے بڑھ گیا۔ اگلے روز استنبول یونیورسٹی کے ریکٹر ڈاکٹر محموت اے کے سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے مجھے اُس دن کی ہزاروں تصاویر دکھائیں جن میں وہ خود اپنی جامعہ کی دستار فضیلت پہنچے اس تاریخی شہر کی سڑکوں پر ہزاروں اساتذہ کے جلوس کی قیادت کرتے دکھائی دیے۔’’ وہ کیسا جذبہ تھاجس نے مزدور، استاد، تاجر ،شاعر، اداکار اور قوم کے ہر فرد کو ایک ہی لڑی میں پرو دیاتھا؟‘‘۔یہ سوال میں نے اپنے پیارے دوست ڈاکٹر خلیل طوقار سے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسے اور کہا کہ لو سنو! پھر انھوں نے مجھے اپنی کہانی سنا ئی۔ باتیں کرتے کرتے ہم ان کے فلیٹ سے نکلے اور ٹہلتے ہوئے عُمرانیہ بیلے دیسی یعنی بلدیہ کے عظیم الشان کمپلیکس کے سبزہ زار کی خوشبوئیں لیتے ہوئے ذرا آگے یعنی لاہور کی انارکلی کی طرح ہنستے بستے اُسکے در کو چھوتے ہوئے بازار تک آپہنچے پھر اس راستے کی طرف ہولیے جو باسفورس برج کی طرف جاتا ہے۔
’’ اس شب میں بہ وجہ ہجوم بس یہاں تک ہی پہنچ پایاتھا‘‘۔
خلیل طوقار نے ایک جگہ کی نشان دہی کی تو میں نے سوال کیا کہ جب گولیاں چل رہی تھیں اور لوگ ٹینکوں تلے کچلے جارہے تھے تو ایسے میں لازم تھا کہ آپ گھر میں آرام سے بیٹھتے۔’’ ہونا تو یہی چاہئے تھا لیکن جب ہمارے صدر نے عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی تو نہ صرف میرے لیے بلکہ کسی کے لیے بھی گھر میں پڑے رہنا ممکن نہ رہا۔ہمارا خیال تھا کہ اب تخت یا تختہ۔ کچھ بھی ہواب ہارنا نہیں، ہراناہے، پھر کچھ ایسا ہوا کہ نہتے نوجوانوں نے بھاری بھرکم ٹینک ناکارہ بنادیے اور عوام پر گولیاں برسانے والوں کو اُن کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔کچھ ایسا ہی ماحول تھا جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب گھر میں بیٹھے رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔بس، میں نے دودھ پیتے بیٹے کے ماتھے پربوسہ دیا، بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بیوی کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل پڑا۔گلی کوچے ہمسائیوں سے بھرے ہوئے تھے ۔ہماری پڑوسن دو جوان بیٹیوں سمیت گھر سے باہر کھڑی کہہ رہی تھی کہ یہ وقت گھر میں پڑے رہنے کا نہیں۔میں کچھ آگے گیا تو میری بیوی بھی بچوں کو اللہ کے سپرد کرکے میرے شانہ بہ شانہ کھڑی تھی‘‘۔
’’مگر سوال پھر وہی ہے کہ آخر یہ جذبہ پیدا کیسے ہوا؟‘‘۔
’’ جذبہ یہ تھا کہ یہ قوم اب کسی کی غلام نہیں بنے گی‘‘۔
’’کیسی غلامی؟‘‘۔
اس کا سبب یہ ہے کہ جب منتخب حکومتوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے تو پھر قانون ؛ قانون نہیں رہتا،جابر کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بن جاتا ہے۔مجھے یاد ہے کہ 1980ء میں جب مارشل لالگایا گیا تو 17؍ برس کے ایک بچے کو اٹھارہ برس کا قرار دے کر پھانسی دے دی گئی ۔ساٹھ کی دہائی میں عدنان میندریس موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے۔ اس بار تو سازشی ٹولہ عوام پر بھی کھلے عام جہازوں سے بمباری کررہا تھا۔ ہمیں صاف دکھائی دیتا تھا کہ ہماری منتخب قیادت کے ساتھ بھی ایک بار پھر وہی کچھ ہونے والا ہے۔ خلیل طوقار کی بات بھی میں نے پلو سے باندھ لی لیکن چند روز کے بعد جب ضلع عمرانیہ کے میئر حسن جان سے ملاقات ہوئی اور انھوں نے مجھے اپنے شہر کے بارے میں بتایا، شہر والوں کے بارے میں بتایا، شہر کی تاریخ سے آگاہ کیااور پھر بتایا کہ کس طرح انھوں نے ازمنۂ وسطیٰ کی ٹیڑھی میڑھی اور تاریک گلیوں کو روشن اور سیدھا کردیا، بنیادی ضرورتیں لوگوں کے گھر کی دہلیز پر پہنچا دیں تو لوگوں کے دل بھی ان کے ساتھ دھڑکنے لگے۔دس منٹ کی ملاقات جب ایک گھنٹے سے بڑھی اور ڈیڑھ گھنٹے سے بھی نکلتی دکھائی دی تو میں نے ان سے اجازت چاہی۔ برادر حسن جان ازراہ محبت میرے ساتھ چلتے ہوئے کمپلیکس کی راہ داری تک آئے ، بڑی سی گاڑی دکھائی اور بتایا کہ صرف ان کی بلدیہ میں نہیں،شہر کے گلی کوچوں میں ایسی ہزاروں گاڑیاں متحرک ہیں جو کسی مریض کی ایک ٹیلی فون کال پر چند منٹ میں اسے گھر سے اٹھا کر اسپتال پہنچا دیتی ہیں ۔لاکھوں نوجوانوں کوبہ یک وقت ہنر سکھائے جاتے ہیں، روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اور جب تک روزگار نہیں ملتا ،ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔
’’یہ سب کچھ بلدیہ کرتی ہے؟‘‘۔
’’پھر اور کون کرے؟‘‘۔حسن جان کے جوابی سوال پر میں خاموش ہوگیا۔ 15؍ جولائی کی خون آشام رات کا رازبھی میری سمجھ میں آچکا تھا۔
Tuesday, November 19, 2024
’’اون بیش تین موز‘‘
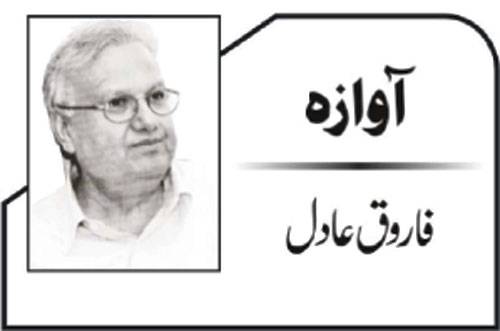
بانی نے بتایا پہلے آپ تھوڑے غلام تھے، اب مکمل غلام بن چکے:علیمہ خان
Nov 19, 2024 | 17:13
پاکستان: پولیو وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ
Nov 19, 2024 | 17:02
'یہ میرا شو ہے'، بادشاہ نے ہانیہ عامر کو اپنے کانسرٹ میں دیکھ کر یہ کیوں کہا؟
Nov 19, 2024 | 16:28
وزیراعظم سے سعودی نائب وزیر داخلہ کی ملاقات
Nov 19, 2024 | 16:25
-
بشریٰ بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا ...
-
بشریٰ بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا ...
-
سابق گورنر سندھ نے پی ٹی آئی والوں کو بڑے خطرے سے خبردار کردیا۔
-
عمران کو بچانے کیلئے کوئی مخلص نہیں: فیصل واوڈا
-
میرا قائد میاں محمد نواز شریف، میرا محسن، ایک محب وطن، خدا ترس ...
-
خاتون ٹیچر کے ڈانٹنے پر طالبعلموں نے کرسی پر بم لگا دیا
ای پیپر دی نیشن
معیشت میں بہتری کے دعوے اور عوام کی حالتِ زار
Nov 19, 2024
پی ٹی آئی کا اسلام آباد پر دھاوا بولنے کا منصوبہ
Nov 19, 2024
دھی رانی اورمعذور وں کی بحالی کے پروگرام
Nov 18, 2024
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
عوام کو ریلیف دے کر ہی خانہ جنگی کا راستہ روکا جاسکتا ہے
-
مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے
-
موجودہ حالات ملک میں فوری انتخابات کے متقاضی ہیں
-
بجلی کے بعد پٹرول بم مجبور عوام جائیں تو جائیں کہاں
باس اور لیڈر
Nov 19, 2024
وزیراعلیٰ پنجاب کا دھی رانی پروگرام
Nov 19, 2024
بتوں سے تجھ کو امیدیں۔۔۔
Nov 19, 2024
موسمیاتی قیامت : وزیر اعظم کی عالمی لیڈروں کو وارننگ
Nov 19, 2024
کوئی لاش گرے، کوئی خون بہے، کوئی بات بنے!
Nov 19, 2024
مسلم ممالک کو اتفاق واتحاد کی دعوت
Nov 19, 2024
از۔۔۔ ظہیرالدین بابر وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب میں ہونے والی کانفرس میں جس طرح غزہ میں ڈھائے جانے والی اسرائیل مظالم ...
وی پی این کی بندشاورصارفین کی پرائیویسی
Nov 19, 2024
کیا صدر ٹرمپ اپنے کیے ہوئے وعدے ایفا کر سکیں گے؟
Nov 19, 2024
منگل‘ 16 جمادی الاول 1446ھ ‘ 19 نومبر2024
Nov 19, 2024
پیر‘ 15 جمادی الاول 1446ھ ‘ 18 نومبر2024ء
Nov 18, 2024
اتوار‘ 14 جمادی الاول 1446ھ ‘ 17 نومبر2024
Nov 17, 2024
ہفتہ،13جمادی الاول 1446ھ16نومبر 2024
Nov 16, 2024
جمعۃ المبارک،12جمادی الاول 1446ھ15نومبر 2024
Nov 15, 2024
ماحولیاتی آلودگی(۲)
Nov 19, 2024
ماحولیاتی آلودگی(۱)
Nov 18, 2024
درخت لگانے کے فوائد اور اہمیت
Nov 17, 2024
اسلامی معاشرے کے عوامل (2)
Nov 16, 2024
اسلامی معاشرے کے عوامل (1)
Nov 15, 2024
فرمان قائد
Nov 19, 2024
جلسہ عام ڈھاکہ 21 مارچ 1948
Nov 19, 2024
فرمان قائد
Nov 18, 2024
رائٹر کے نمائندے سے انٹرویو 25 اکتوبر 1947ء
Nov 18, 2024
فرمان قائد چ
Nov 17, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 19, 2024
بالِ جبریل
Nov 19, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 18, 2024
بانگ ِ درا
Nov 18, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 17, 2024
نیوز لیٹر سبسکرپشن
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 41
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Invalid argument supplied for foreach()
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 42
اشتہار
رابطہ

NIPCO House, 4 - Shaharah e Fatima Jinnah
Lahore Pakistan
Tel: +92 42 36367580 | Fax : +92 42 36367005
Nawaiwaqt Group | Copyright © 2024