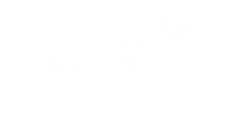مضبوط ادبی ستون غلام عباس کو اْردو افسانوں سے دلچسپی رکھنے والا کون نہیں جانتا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ: ’’جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا‘‘ اسی طرح جس نے ’’آنندی‘‘ نہیں پڑھا وہ اْردو ادب سے واقف نہیں۔ غلام عباس کا آزادی سے قبل کے ماحول میں رچا بسا ایک افسانہ ’’رینگنے والے‘‘ بھی ہے۔ اس کا مرکزی موضوع ایک گلی ہے جہاں ایک انگریز عورت کی ’’بے حرمتی‘‘ ہو جاتی ہے اسی طرح جس طرح آجکل بڑی بڑی دیوہیکل گاڑیوں کی سگنل کاٹنے سے روکنے پر ہو جاتی ہے اور وہ اہلکار کو روند کر بڑھ جاتی ہیں۔ ویسے بڑی گاڑیوں کا بھی کیا اعتبار آپ تمام ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہوئے جا رہے ہوں پھر بھی پیچھے سے اچانک آ لیتی ہیں اور پھر ’’مانگ کیا مانگتا ہے‘‘ کا نعرہ امیرانہ‘‘ لگا کر نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیتی ہیں یہ نوٹ سمیٹنے کے لئے آپ اس دنیائے فانی میں موجود نہیں ہوتے چنانچہ آپ کے سوگوار لواحقین کو یہ ’’فریضہ‘‘ انجام دینا پڑتا ہے۔ خیر انگریز عورت سے ’’بے حرمتی‘‘ والی گلی کے حوالے سے سزا یہ مقرر ہوتی ہے کہ وہاں سے جو بھی گزرے گا وہ جسم و جان چاہے بچا کر چلے یا نہ چلے اسے گرد و غبار میں اٹ کر رینگ کر جانا ہوگا یعنی ’’ایک گرد کا دریا ہے اور خوب کپڑوں پر مل کے جانا ہے‘‘ سکول کے دو بچے یہ ’’سنگدلانہ کھیل‘‘ دیکھنے کے لئے چلے آتے ہیں اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر ایک دھان پان بزرگ کو رینگتے دیکھ کر انکی آنکھیں بھر آتی ہیں۔
کہنے کو تو وطن عزیز کو آزاد ہوئے 77 برس گزر گئے لیکن عوام ہیں کہ انکے سفر زندگی کو درپیش ’’گرد سے اٹی‘‘ گلیاں ہی ختم ہونے میں نہیں آرہیں۔ انصاف کی فراہمی ہو یا صحت کا معاملہ، تعلیمی ضرورت ہو یا رزق کا حصول ،روز مرہ زندگی سے متعلق چھوٹے موٹے کام، ہر معاملہ ’’گرد سے اٹی گلی کی طرح منہ کھولے کھڑا ہے۔ انگریز نے تو گرد سے اٹی ایک گلی کا انتخاب کیا تھا لیکن قیام پاکستان کے بعد تو روزانہ گرد سے اٹی دو تین گلیوں سے گزر کر صبح سے شام کرنا عوام کا معمول بن چکا ہے اور نامرادی کا یہ عالم ہے کہ اب یاد نہیں، تْو بھی شامل تھا کبھی میری تمناؤں میں‘‘ کے مصداق معصوم سی آنکھیں بھی کہیں دستیاب نہیں ہوتیں جو اس مسلسل ذلت پر آنسو بہا سکیں کہ ’’چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اْٹھا کے چلے‘‘ یعنی سب کو اپنے اپنے حصے کا اتنا رینگنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس کسی کے لئے سر اْٹھا کر دیکھنے اور آنسو بہانے کی فرصت نہیں۔ صورتحال دیکھ کر اکثر یہ سوال سر اْٹھانے لگتا ہے کیا ہم نے آزادی محض اس لئے حاصل کی تھی کہ کسی جگہ کا نام ’’آزادی چوک‘‘ رکھ لیں اور حقیقت میں مٹھی بھر اشرافیہ کروڑوں عوام کا ناطقہ بند کر دے؟
ہم نے یقیناً آزادی ایک ایسی سرزمین کے حصول کیلئے حاصل کی تھی جو تھامس مور کے یو ٹوپیا سے مشابہہ تھی جہاں ہم نے اپنے عقائد اور تجربات کے مطابق زندگی گزارنا اور اسے اچھائیوں کی ’’تجربہ گاہ‘‘ بنانا تھا کسی کو تکلیف دینا تو درکنار سوچنا بھی گناہ تھا لیکن جھوٹی آن بان اور شان کے حصول میں مبتلا اور دولت کی اسیری میں گرفتار ہو کر یہ ہم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ ہم مکروہ خواہشات کی گرد سے اتنے اٹ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا ہے اور اس سب کے باوجود گھناؤنی ناپاک خواہشوں کی تکمیل کے خنجر سے ایک دوسرے کا گلا کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔
مجھے داستان امیر حمزہ کے عمرو عیار کی زنبیل یاد آگئی کہ جس کا شکم بھرتا ہی نہ تھا۔ یقیناً ہم بھی دوزخی پیٹ بھرنے کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسی بیماری جس کے اسیر کیلئے سکون تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ نیچے کھڑے ہو کر درخت کاٹنا تو اور بات لیکن کسی شاخ پر بیٹھ کر اسی کی تباہی کا سامان کرکے بھلا کون سکون سے رہ سکتا ہے۔اس بیماری سے بہتر تھا ہم انتظار حسین کے ’’بندروں ‘‘ میں تبدیل ہو جاتے۔ درخت کی کسی شاخ پر تو سکون کی نیند لے رہے ہوتے لیکن اب ہمیں نہ دن کو چین ہے نہ رات کو سکون میسر ہے۔ کیلکولیٹر بن کر رہ گئے ہیں۔
مجھے چیتھڑوں میں لپٹے اس بچے کی تصویر بھی بہت ستاتی ہے جس میں وہ بھرپور عقیدت سے اشرافیہ کے کسی معزز رکن کو اپنی یا باپ کی ہفتہ بھر کی کمائی پکڑانے میں مصروف ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد اس کے دکھوں کا مداوا ہو جائے گا۔ وہ اور اس کا خاندان کم از کم ’’رینگنے‘‘والوں کے درد سے نکل کر انسانوں کی قطار میں شمار ہونے لگیں گے۔ خون پسینے کے ٹیکسوں کی رقم سے اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو مفت بجلی، گیس، پانی، پٹرول، جہازی سائز کی گاڑیاں (جو انہیں ہی روندنے سے نہیں چوکتیں) اور محلات نما رہائشیں دینے والے عوام بھی اس چیتھڑوں میں لپٹے بچے سے کم نہیں۔
حیرت ہے گھناؤنی خواہشات کے لئے دوسروں کو کچل دینے والے طاقتور لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ان رینگنے والوں کے بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو صبح سویرے انہیں صرف اپنی ناتواں دعاؤں کے سہارے ہی رزق کی تلاش میں بھیج پاتے ہیں اور شام کو اگر یہ کسی نا پاک خواہش کی بھینٹ چڑھ جائیں، راستہ گم کر بیٹھیں، گھر نہ پہنچ پائیں یا پھر جان دیدیں اور یوٹیلٹی بلز نہ دے پائیں تو ان کا انتظار کرنیوالوں پر کیا گزرے گی، کیا وہ جیتے جی مر نہیں جائیں گے، کیا ایسے ناداروں کی اولاد معاشرے کے صحتمند شہری بن پائے گی اور کیا امیدوں سے بھری روشن آنکھوں والی قوم میں تبدیل ہو سکے گی یا ایسی بھگدڑ میں بدل جائے گی کہ جسے دیکھ کر جنگل کا قانون بھی شرمائے گا؟ انتہائی بے بسی اور ناداری کے باوجود ہر شخص جینے کی تمنا رکھتا ہے۔ مجھے ایک سندھی ڈرامہ یاد ہے کہ جس کی ہیروئین دو یا تین بچوں کی ماں بیماری کے ہاتھوں زندگی کی جنگ ہار رہی ہوتی ہے اور اس کا باپ اسے تسلی دینے کیلئے کہتا ہے کہ ’’تم جب اس دنیا سے جاؤ گی تو فرشتے پروں پر اٹھا لیں گے اور پھر سارے سکھ تمہارا مقدر ہوں گے۔ وہ عورت غیر یقینی انداز میں پوچھتی ہے کہ ’’کیا واقعی پھر سارے سکھ میرے ہوں گے، تو اس کا والد اپنے آنسو چھپا کر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے کہ ’’کیوں نہیں‘‘ تم نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا ‘‘ وہ خاتون امید بھرے لہجے میں کہتی ہے کہ اگر مرنے کے بعد سارے سکھ مجھے مل جائیں گے تو کیا کچھ عرصہ مزید اپنے بچوں کے پاس یہ دکھ بھری زندگی نہیں گزار سکتی؟
ایک قوم بننا ہے، ملک آگے بڑھانا ہے اور سکھ، چین کی منزل پانی ہے تو سب کو ساتھ لیکر چلیں اور سب کے ساتھ مل کر چلیں۔ خالی باتوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مشکل وقت میں دوسروں کو قربانی کا درس نہ دیں، اتر آئیں جہازی سائز گاڑیوں سے نیچے، چھوڑ دیں محلات نما گھر، پروٹوکول کے چونچلے، مفت خوریاں اور عوام میں مل جائیں… مشکل وقت سانجھی قربانیاں دیکر برداشت کریں پھر بچے گا ملک۔ پھر بنے کی قوم… اور عوام میں امید کی کرن کروٹ لے گی۔ ورنہ (خیپل دی بلڈر) Khipil the Builderکہانی میں محلات کے خواب دکھا کر محض باتیں تو خیپل بھی بہت بنایا کرتا تھا لیکن پھر سب دھڑام ہو گیا۔
بقول فیض، عوام میں کل کی امید جگائیں۔
مری جاں آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے تب وقت نے
کسی اپنے کل میں بھی بھول کر کہیں لکھ رکھی ہوں چند مسرتیں
٭…٭…٭
Tuesday, November 19, 2024
رینگنے والے …

حرمین شریفین میں بچوں کی حفاظت کیلئے اہم اقدام
Nov 19, 2024 | 01:24
بھارت نے میٹا پر بھاری جرمانہ عائد کردیا
Nov 19, 2024 | 01:18
مالی سال کی پہلی سہ ماہی: بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 0.8 فیصد کمی ریکارڈ
Nov 19, 2024 | 00:57
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ
Nov 19, 2024 | 00:18
-
پنجاب، اسموگ کم ہوتے ہی ہوٹلوں کے اوقات کار میں نرمی
-
پنجاب، اسموگ کم ہوتے ہی ہوٹلوں کے اوقات کار میں نرمی
-
الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس ختم کردی گئی
-
آسٹریلیا کیخلاف تیسرا ٹی 20، محمد رضوان پلیئنگ الیون سے باہر
-
لاہور، لنڈا بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا
-
24 نومبر کو غلامی سے نجات کےلیے نکلنا ہے، علیمہ خان
ای پیپر دی نیشن
معیشت میں بہتری کے دعوے اور عوام کی حالتِ زار
Nov 19, 2024
پی ٹی آئی کا اسلام آباد پر دھاوا بولنے کا منصوبہ
Nov 19, 2024
دھی رانی اورمعذور وں کی بحالی کے پروگرام
Nov 18, 2024
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
عوام کو ریلیف دے کر ہی خانہ جنگی کا راستہ روکا جاسکتا ہے
-
مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے
-
موجودہ حالات ملک میں فوری انتخابات کے متقاضی ہیں
-
بجلی کے بعد پٹرول بم مجبور عوام جائیں تو جائیں کہاں
باس اور لیڈر
Nov 19, 2024
وزیراعلیٰ پنجاب کا دھی رانی پروگرام
Nov 19, 2024
بتوں سے تجھ کو امیدیں۔۔۔
Nov 19, 2024
موسمیاتی قیامت : وزیر اعظم کی عالمی لیڈروں کو وارننگ
Nov 19, 2024
کوئی لاش گرے، کوئی خون بہے، کوئی بات بنے!
Nov 19, 2024
مسلم ممالک کو اتفاق واتحاد کی دعوت
Nov 19, 2024
از۔۔۔ ظہیرالدین بابر وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب میں ہونے والی کانفرس میں جس طرح غزہ میں ڈھائے جانے والی اسرائیل مظالم ...
وی پی این کی بندشاورصارفین کی پرائیویسی
Nov 19, 2024
کیا صدر ٹرمپ اپنے کیے ہوئے وعدے ایفا کر سکیں گے؟
Nov 19, 2024
منگل‘ 16 جمادی الاول 1446ھ ‘ 19 نومبر2024
Nov 19, 2024
پیر‘ 15 جمادی الاول 1446ھ ‘ 18 نومبر2024ء
Nov 18, 2024
اتوار‘ 14 جمادی الاول 1446ھ ‘ 17 نومبر2024
Nov 17, 2024
ہفتہ،13جمادی الاول 1446ھ16نومبر 2024
Nov 16, 2024
جمعۃ المبارک،12جمادی الاول 1446ھ15نومبر 2024
Nov 15, 2024
ماحولیاتی آلودگی(۲)
Nov 19, 2024
ماحولیاتی آلودگی(۱)
Nov 18, 2024
درخت لگانے کے فوائد اور اہمیت
Nov 17, 2024
اسلامی معاشرے کے عوامل (2)
Nov 16, 2024
اسلامی معاشرے کے عوامل (1)
Nov 15, 2024
جلسہ عام ڈھاکہ 21 مارچ 1948
Nov 19, 2024
فرمان قائد
Nov 18, 2024
رائٹر کے نمائندے سے انٹرویو 25 اکتوبر 1947ء
Nov 18, 2024
فرمان قائد چ
Nov 17, 2024
پریس کانفرنس 14 جولائی 1947
Nov 17, 2024
بالِ جبریل
Nov 19, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 18, 2024
بانگ ِ درا
Nov 18, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 17, 2024
بالِ جبریل
Nov 17, 2024
نیوز لیٹر سبسکرپشن
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 41
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Invalid argument supplied for foreach()
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 42
اشتہار
رابطہ

NIPCO House, 4 - Shaharah e Fatima Jinnah
Lahore Pakistan
Tel: +92 42 36367580 | Fax : +92 42 36367005
Nawaiwaqt Group | Copyright © 2024