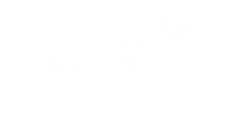بے یقینی، اداسی اور مایوسی کے ماحول میں گھرے شکسپیئر کے ڈرامے ”ہیملٹ“ کا مرکزی جملہ ”ایسا کر دینا چاہئے یا نہیں “ (To be or not to be) وہ شاہکار ہے جس پر ادبی تنقید اور بحث کی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی۔ ہیملٹ کا باپ ڈنمارک کا بادشاہ قتل ہو جاتا ہے۔ اس کی روح ہیملٹ سے ملکر بتاتی ہے کہ اس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے جو تخت پر براجمان ہے۔ یہ سن کہ ہیملٹ اپنے چچا کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگتا ہے لیکن موقع ملنے پر ڈگمگا جاتا ہے اور وسوسوں میں گِھر جاتا ہے۔
یوں تو ہر انسان کی زندگی امکانات اور خدشات سے لبریز ہوتی ہے اور سکھ، دکھ، دھوپ چھاو¿ں کی طرح آتے جاتے ہیں لیکن ہم پاکستانی بے یقینی، اداسی، مایوسی کے کچھ زیادہ ہی ہمسفر ہوتے چلے جا رہے ہیں 47ءکی پہلی نسل سے تیسری نسل تک نازک ادوار کی گردان کیساتھ بے یقینی، اداسی اور مایوسی کی ”نیاز“ اس قدر بٹی ہے کہ اب ذہن اور دہن باقی ذائقوں کا مزا بھولتے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب زندگی کی نامہربانیوں کے مخمصے میں پھنس کر بے یقینی کے ایسے ”ہیملٹ“ بن چکے ہیں کہ کبھی کبھار ملنے والا اعتماد بھرا ”دلاسہ بھی ہمارے منہ کا ذائقہ بدلنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ نامرادی کا یہ عالم ہے کہ اب یاد نہیں کہ ہم نازک دور میں رہتے ہیں یا ہمارے اندر نازک دور نے مستقل بسیرا کر رکھا ہے جب گریبانوں کے چاک ہونے کے طویل سفر سے گزر کر بھی فصل گل نہ آئے تو ایسا ہو جانا اچنبھے کی بات نہیں۔
بے یقینی، اداسی اور مایوسی وہ شک بھرا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے دھندلکے میں کسی اور کا تو درکنار اپنا چہرہ بھی صحیح طرح دکھائی نہیں پڑتا۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم انسانوں کی بجائے فرانز کافکا کی کہانی (Metamorphosis)جیسا کیکڑا بن چکے ہیں تو کبھی اپنا آپ انتظار حسین کے افسانے کایا کلپ کے شہزادہ آزاد بخت جیسا دکھائی پڑتا ہے جو بار بار ہئیت بدلنے سے مستقل طور پر مکھی بن گیا تھا۔
ڈیوڈ پارمرز (David palmers)کی کتاب ریلیٹی پلس ( Plus Reality) یاد آ گئی جس میں زمانہ قدیم کے ایک فلاسفر ڑوانگ ڑی کا ذکر ہے جس نے خواب دیکھا کہ وہ مکھی بن گیا ہے اور پھر ساری عمر اس وہم میں مبتلا رہ کر گزار دی کہ اس نے خواب میں خود کو مکھی بنتے دیکھا تھا یا کوئی مکھی خواب میں اسے انسان بنا دیکھ رہی ہے۔ سورج کا کام روشنی بانٹنا ہے لیکن اگر سورج ہی اندھیروں کا رکھوالا بن جائے تو منزلیں سفر کی صعوبتوں میں کہیں دم توڑ دیتی ہیں جاذب نے کہا خوب کہا ہے
کتنا اندھیر مچا دیتا ہے دن کو سورج
آسمان پر نظر ہی نہیں آتا ستارہ کوئی
ہمارے سورجوں نے تو اندھیر مچایا ہی تھا لیکن ہم ستارے بھی تاریکیوں کے ہم سفر بن کر سورجوں کے ساتھی بن گئے ہیں۔ اب دعا یاد ہے نہ حرف دعا یاد رہا ہے ہمیں کیا ہو گیا جو داغ داغ اجالے کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ بھی فراموش کر دیا ہے کہ اچھے معاشرے کی تشکیل بھی کبھی ہماری تمناو¿ں میں شامل تھیں اورکبھی ہم بھی سوچا کرتے تھے کہ ہمیں ماتھے پر خود اعتمادی کا بوسہ لیکر جگنوو¿ں کے تتلیوں کے دیس جانا ہے۔ ہماری اس ناخوشگوار کیفیت کے ذمہ دار کون ہیں وہ کون سے ہاتھ ہیں وہ کون سے ذہن ہیں جنہوں نے خوش رہنے والے ملکوں کی قطار میں گھیسٹ کر ہمیں 108 ویں درجے تک گرا دیا ہے اور اس پر بس نہیں کر رہے۔
کیا اس سب کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں جو عوام کی پہنچ سے کئی قد آدم دور عالیشان محلات میں محفوظ ہیں اور عوام کو محض جذباتی نعروں کے ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کبھی ووٹ کو عزتیں دے رہے ہیں تو کبھی حقیقی آزادیوں کے ٹوکن بانٹ رہے ہیں اور کبھی ہر گھر سے نکلنے کی دہائی مچا رکھی ہے۔
کیا پھر وہ ہیں جو کریز سے نکل کر کھیلنے کے عادی ہو چکے ہیں یا وہ جنہوں نے ترازو پکڑنے والے کی آنکھوں سے پٹی اتار کر ہماری عقلوں پر منڈھ دی ہے اور انصاف کے منتظر لوگوں کو وعدہ فردا کی امید پر چھوڑ دیا ہے یا پھر وہ مخلوق جسے اچھا بھلا انسان پیدا کیا گیا تھا لیکن گورے آقاو¿ں نے بندر کی طرح اکڑ کر چلنا سکھا دیا گورے تو چلے گئے لیکن ”اکڑ“ ابھی تک باقی ہے بلکہ پہلے سے بھی توانا ہو کر خلق خدا پر لاٹھی کی طرح برس رہی ہے یہ لاٹھی کبھی منٹو کے نئے قانون کا سہارا لیکر کوڑا بھی بن جاتی ہے اور ناتوانوں کے جسموں پر تازیانے لگا لگا کر کہتی ہے کہ ”اپنی حد میں رہو کوئی آزادی نہیں، قانون وہی پرانا ہے“۔
ہماری اداسیوں، بے یقینیوں اور مایوسیوں میں یقیناً ان سب کا بہت کردار ہوگا لیکن کبھی سوچا ہے کہ ستاروں کی طرح اجالوں سے چھپنے میں کوئی کسر ہم نے بھی نہیں چھوڑی۔ ہمارے دفاتر آسانیاں پیدا کرنے کے مراکز نہیں بلکہ سٹاک ایکسچینج بن چکے ہیں جہاں ہر کام کا ریٹ پل پل بدلتا ہے۔ ہسپتالوں میں بستر اسے ہی میسر آتا ہے جو جیب ڈھیلی کرے، تعلیم کا یہ حال ہے کہ اس کا کوئی حال ہے نہ مستقبل....
ہم تو گوشت اور سبزیوں کو بھی پانی لگا لگا کر وزنی کرنے کے طریقے سیکھ چکے ہیں پانی ملانا تو ماضی ہوا اب دودھ کے نام پر زہر بیچنا کوئی ہم سے سیکھے اور ادویات میں ملاوٹ کرکے جھوٹی خوشحالی کی سیڑھی چڑھنا کیا ہوتا ہے ہم ہی تو بتا سکتے ہیں۔
اپنے معاشرے میں آسمان کو چھوتی بداعتمادی اور نفسانفسی کی فضا دیکھ کر میکسیکو کے ادیب گریگور ریولو کا افسانہ ”خدا کے نام خط“ذہن کی سکرین پر رقص کرتا محسوس ہوتا ہے جو ایک کسان کی کہانی ہے یہ کسان فصل اچھی نہ ہونے پر فاقوں کے خوف سے خدا کو خط لکھتا ہے کہ اسے ”100پیسو“ درکار ہیں ڈاکخانے والے خط دیکھ کر ترس کھاتے ہوئے آپس میں پیسے جمع کرتے ہیں جو ”70 پیسو“ بنتے ہیں اور کسان کے پتے پر منی آرڈر کر دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں ”خدا کی طرف سے“ کسان منی آرڈر پاکر خوش تو ہوتا ہے لیکن مطمئن نہیں وہ خدا کو ایک اور خط لکھتا ہے کہ پیسے بھیجنے کا شکریہ لیکن آئندہ پیسے ڈاک کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست بھیجنا کیونکہ ڈاکخانے والے بھی دوسروں کی طرح ”چور“ ہیں اور انہوں نے 30 پیسو خود رکھ کر مجھے صرف 70 پیسو دیئے ہیں۔ جس طرح ہر چیز کا اپنا رنگ ہوتا ہے اسی طرح غلط کاموں کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے دوسروں کی خوشیاں چھین کر اپنے لئے مسرتیں خریدنے کی کوشش کرنے کا رنگ معاشرے پر چڑھ کر اسے اداس، مایوس اور بے یقین بنا دیتا ہے اور اسے بے مقصدیت کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے نکلنے کی ہر کوشش اصل میں مزید پھنسنے کی سعی بن جاتی ہے۔
کبھی کچھ لمحوں کیلئے آنکھیں بند کرکے سچائی، امید، اعتماد اور خوشیوں کی دستک بھی سنیں اور اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کیلئے ایک بااعتماد، صحتمند اور مسکراتے ہوئے معاشرے کی تشکیل کیلئے توانائیاں وقف کر دیں۔یہ نہ سوچیں کہ کون کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ایسا نہ کیا تو بانس رہے گا نہ کبھی بانسری بجے گی بلکہ پورا آشیانہ ہی ڈھے جائیگا یا کسی نہ ختم ہونیوالی دلدل میں دھنستا چلا جائیگا۔
آخر میں حالی کا شعر
فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا
مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ
Sunday, November 24, 2024
خوشیوں کا گرتا ہوا گراف

خان کی رہائی:شیر افضل مروت کا اپنی پارٹی کو انوکھا مشورہ
Nov 24, 2024 | 14:29
تحریک انصاف کا احتجاج:منہ توڑ جواب دیںگے، وزیر دفاع کا بڑا اعلان
Nov 24, 2024 | 14:20
پشاور موٹروے اچانک پولیس کی جانب سے کھول دی گئی۔
Nov 24, 2024 | 14:19
اسرائیل کے غزہ اور لبنان پر حملےجاری،54سے زائد شہید
Nov 24, 2024 | 14:07
-
عوام اور انکی املاک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے:آئی جی اسلام آباد
-
عوام اور انکی املاک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے:آئی جی اسلام آباد
-
لاہور،پولیس کا کریک ڈاؤن ،پی ٹی آئی انفارمیشن سیکرٹری حافظ ...
-
پی ٹی اے کا وی پی این کی بندش کے دوسرے ٹرائل کا آغاز
-
پی ٹی آئی احتجاج،کے پی قافلے 2بجے روانہ ہونگے
-
پی ٹی آئی احتجاج کی کال:پاکستان ریلوے کی بک ٹکٹیں منسوخ،تمام ...
ای پیپر دی نیشن
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
عوام کو ریلیف دے کر ہی خانہ جنگی کا راستہ روکا جاسکتا ہے
-
مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے
-
موجودہ حالات ملک میں فوری انتخابات کے متقاضی ہیں
-
بجلی کے بعد پٹرول بم مجبور عوام جائیں تو جائیں کہاں
مفت مشورے
Nov 24, 2024
پاکستان میں دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوتی
Nov 24, 2024
ظہور عالم شہید
Nov 24, 2024
صحت کے میدان میں حکومتی اور انفرادی کاوشیں
Nov 24, 2024
کتاب دوستی اور کتاب دشمنی
Nov 24, 2024
فتوی ساز فون ہیکرزاور درپیش ایشوز پر متحرک کیوںنہیں ہوتے؟
Nov 24, 2024
ٹی ٹاک …طلعت عباس خان ایڈووکیٹ takhan_column@hotmail.com وی پی این ( ورچوئل پرائیوٹ نیٹ ورک) کے استعمال کو اسلامی نظریاتی کونسل نے ...
24 نومبر کال کا اعلان اور حکومتی اقدامات
Nov 24, 2024
پاک فضائیہ… عظمتوں و سیادتوں کی داستان
Nov 24, 2024
سرکاری اسپتالوں کا ایمرجنسی اسٹاف قابلِ تعریف ہے
Nov 23, 2024
اتوار‘ 21 جمادی الاول 1446ھ ‘ 24 نومبر2024
Nov 24, 2024
24ہفتہ ‘ 20 جمادی الاول 1446ھ ‘ 23 نومبر2024
Nov 23, 2024
جمعۃ المبارک ‘ 19 جمادی الاول 1446ھ ‘ 22 نومبر2024ء
Nov 22, 2024
جمعرات،18جمادی الاول 1446ھ 21 نومبر 2024
Nov 21, 2024
بدھ‘ 17 جمادی الاول 1446ھ ‘ 20 نومبر2024
Nov 20, 2024
دنیا سے بے رغبتی
Nov 24, 2024
فضائل و بر کات نام محمد(۲)
Nov 23, 2024
فضائل و بر کات نام محمد ﷺ(۱)
Nov 22, 2024
معاشی خود انحصاری (2)
Nov 21, 2024
معاشی خود انحصاری (۱)
Nov 20, 2024
فرمان قائد
Nov 24, 2024
جلسہ عام ڈھاکہ 28 مارچ 1948
Nov 24, 2024
فرمان قائد
Nov 23, 2024
بحریہ پاکستان سے خطاب 23 جنوری 1948ء
Nov 23, 2024
ڈھاکہ … 31 مارچ 1948ء
Nov 22, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 24, 2024
ضربِ کلیم
Nov 24, 2024
فرمودہ اقبال
Nov 23, 2024
بانگِ درا
Nov 23, 2024
ضربِ کلیم
Nov 22, 2024
نیوز لیٹر سبسکرپشن
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 41
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Invalid argument supplied for foreach()
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 42
اشتہار
رابطہ

NIPCO House, 4 - Shaharah e Fatima Jinnah
Lahore Pakistan
Tel: +92 42 36367580 | Fax : +92 42 36367005
Nawaiwaqt Group | Copyright © 2024